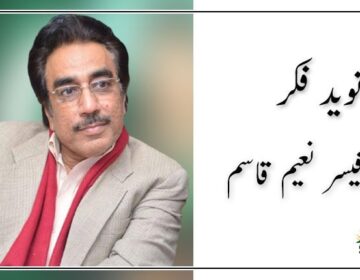اس زمانے میں جبکہ نہ ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے اور اخبار میں سوائے اشتہاروں کے اور کچھ نہیں۔ رسالے اور کتابیں ہی ہماری رفاقت کرتی ہیں۔ ویسے بھی بہت دن سے خواتین کی چند کتابیں مجھے بار بار اکسا رہی تھیں کہ قلم کو بغل سے نکالو اور لکھنا شروع کرو۔ میرے سامنے پہلی کتاب تھی ثمینہ نذیر کی۔کہانیوں کی یہ کتاب بے شمار لسانی تجربے اور موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ حیدرآباد دکن کے علاقے سے ہمارے ملنے والوں میں جیلانی بانو اور بہت سے دیگر مرد و خواتین شامل تھے۔ ان کی تمام تحریریں بھی پڑھی تھیں مگر کسی کہانی میں دکنی اردو کا نمونہ شامل نہیں تھا۔ ثمینہ نذیر نے نہ صرف اس لہجے سے شناسائی پیدا کی، بلکہ وہ ماحول بھی جو پرانے نواب خاندانوں، خادماؤں کے گھرانوں میں بولی جانے والی اردو اور پھر وہ تمام کھانوں کے لوازمات جو حیدرآبادی گھرانوں کے لئے مخصوص ہیں۔ ان سے بھی شناسا کیا۔ ساتھ ہی تحریر کا وہ اسلوب جو اے آر خاتون سے گزر کر عصمت چغتائی کے لحاف پر پہنچ کر بہت عرصے تک نامعلوم دنیا میں گم ہو گیا۔
آج کے آشوب میں ایک کتاب ختم ہوتی ہے تو دوسری سامنے رکھ کر خوب دھیان سے اس لئے بھی پڑھنا پڑھتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ٹی وی اسکرین پر مکروہ چہرے نظر آنے نہ شروع ہو جائیں۔ میری عزیز دوست بہت کم گو مگر بہت زودگو یاسمین حمید کی جنوبی ایشیائی نظمیں سامنے آکے ٹھہر گئیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ انگریزی اور دیگر زبانوں کی شاعری میں بہت مصروف اس لئے بھی ہو گئے تھے کہ اردو کے کافی شاعر نظموں میں نوجوانی کا عشق تو چھوڑ چکے تھے مگر اردگرد کے ماحول، زبانوں، منظر ناموں، ہواؤں کی تھکاوٹ اور غم کو افیون کی طرح دیکھنے کے رستے کو فراموش کرتے رہے۔ جب یاسمین نے لکھا، کاہل آدمی، زمیں کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہو، تو مجھے پورے برصغیر میں موڑھوں پر بیٹھے، حقے کی گڑگڑاہٹ اور کھانسی کی لے کو ملا کر کبھی بابا بلھے شاہ تو کبھی کبیر اور کبھی کنول نرائن یاد آنے لگتے کہ ان کی آدھی زندگی موت کی راہ تکتے گزر جاتی ہے۔ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں ’’چلو ہم جھوٹ اور بددیانتی کے کھیل کو ترک کر دیں۔‘‘ یہ اور ایسے مصرعے کہ ’’بارش کے سانپ سر ِساحل جان بچا کر بھاگتی ہوئی مچھلی کا تعاقب کرتے‘‘ بہت عمدہ کرافٹ کے ساتھ، ترجمہ کیا ہے۔
یاسمین نے انڈیا کی وہ زبانیں جن کا اردو میں ترجمہ کبھی اجمل کمال اور کبھی آصف فرخی نے کیا، ان کی مجموعی شکل دیکھ کر بہت لطف آتا ہے۔ رانا کانتھ مرتھ، اڑیا زبان کے شاعر ہیں۔ جب انہوں نےلکھا ’’میں تمہیں نہیں دیکھ سکا، کیونکہ آندھی میری آنکھیں اڑالے گئی تھی۔ اور میرے الفاظ تمہاری ہم آغوشی میں کہیں کھو گئے تھے۔ مجھے ٹیگور یاد آیا، مجھے امرتہ پریتم یاد آئی۔ جیسے جیسے نظمیں پڑھتی گئی، انسان کے اندر کی گپھائیں شعلہ بار ہوتی گئیں۔ مل یالم کے شاعر پانیکر نے خطرناک کھیل کے عنوان سے نظم لکھی، انجام یہ ہوا کہ چار ٹانگوں، تین ٹانگوں اور دو ٹانگوں والے سارے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور ایک ٹانگ والا رقص کرتا رہ گیا ایسے اشاروں سے نظم اور گھمبیر ہو جاتی ہے۔پورے اس انتخاب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہر زبان، معاشرے کی زبان اور بود و باش مختلف بیانیہ پیش کرتی ہے۔ اس کتاب میں صرف ہندوستان کی علاقائی زبانوں کے تراجم ہی نہیں، نیپالی، ہندی، پنجابی اور انگریزی زبانوں کی شاعری کے تراجم بھی شامل ہیں۔ نیپالی شاعرہ پری جات کہتی ہے ’’گھٹن، بے چینی، کمرے کی فضا پر حاوی ہے۔ جھانسی کی رانی کا تصور جون آف آرک، مادام کیوری، معاشرے سے برسر پیکار‘‘۔
ہر زمانے میں عورت کے ساتھ رویے قدرِ مشترک ہیں۔ ابھی تک میں نے دو خواتین کی تحریروں کا حوالہ دیا ہے۔ باشعور مردوں کے یہاں بھی کینوس اپنے ملک اور اپنی نئی نسل کی سوچ کو انگریزی میں “عدر ڈیز”کے نام سے انگلش میں ناول تحریر ارشد وحید نے کیا ہے۔ پھل جھڑیوں والی، مشکل اور استعاراتی بھاری بھرکم زبان کے بجائے، بالکل سادہ لہجے اور مکالمات پورے ناول میں چلتے ہیں۔ دو جوان لڑکیاں سارا اور ماہین کیسے جوانی سے میچور عمر تک پہنچتی ہیں۔ شادی، علیحدگی، بچے، ان کا جوان ہو کر پاکستان اور لندن میں ایک جیسا ماحول دیکھنا۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہر کسی کو ایجنٹ یا غیر ملکی جاسوس بنا کر اغوا کرنا، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا۔ کچھ بھی نامعلوم ہونے پر اس کے خود اعتمادی لہجے کو دفن کر کے کبھی آزاد کردینا تو کبھی مار کے لاش کو دریا میں بہا دینا۔ یہ ہے ان تمام مردوں کی زندگی جو سوچتے، لکھتے اور فرشتوں کے کہنے پر ناحق، چلتی گاڑی سے اتار کر، زد و کوب کرکے کبھی چھوڑ دیئے جاتے اور کبھی حکم نامہ ملتا ہے کہ فوراً ملک سے نکل جاؤ۔ زندگی آگے بڑھتی ہے اور اب نوجوان نسل سامنے آتی ہے جو اپنے طرز پر زندگی گزارتی، خود مختار رہنا چاہتی ہے مگر ماں، باپ کے رشتوں کو جذباتی سطح پر سوچتی ہے۔ وہ ماں باپ کی علیحدگی کو سمجھنے کے باوجود، باپ کو ڈھونڈ نکالتی اور اس سے ملتے ہوئے یہ بات زیر بحث لاتی ہی نہیں کہ آپ دونوں الگ کیوں ہوئے۔
پورے ناول میں لاہور چھایا ہوا ہے مال روڈ پر ٹہلنے کا زمانہ، میلہ چراغاں، مادھو لال حسین، انار کلی کی چاٹ، دریائے راوی کے سوکھتے کنارے اور بارہ دری کی ویرانیوں میں گزشتہ تاریخ کو یاد کرتی عورتیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے باہر کھڑے لڑکے سائیکلوں پر جاتی لڑکیوں پر کبھی نعرے بازی نہیں کرتے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے۔ استاد دامن، مجید امجد اور پھر حبیب جالب کے مصرعے دہراتے نوجوان۔ یہ تھا لاہور کہ نہر کے کنارے، گرمیوں میں چھلانگیں لگا کر غوطے کھاتے بچے اور کہیں نہر کے آخری کنارے پر کپڑے دھوتی عورتیں۔ بسنت میں چھت سے چھت ملی، اندرون شہر میں پتلی پتلی گلیاں اور چھتوں پر پتنگ اڑاتے نوجوان مرد اور عورتیں۔
مگر پھر 1970 کا زمانہ ایم آر ڈی کی رجعت پسندی، دوسری طرف ترقی پسند۔ انجام کار، مشرقی پاکستان کی علیحدہ مملکت پاکستان کا ایک بازو، چار صوبوں میں منقسم، باہمی نفرتیں، حسد اور حقارتیں۔ مگر ناول نگار، ان سب ابتلائوں کے بیان کرنے کے بعد بھی آسمان پر ہلکی سی روشنی کی لکیر دیکھتا ہے۔ یہی نوجوان نسل کی امید ہے۔
بشکریہ روزنامہ جنگ