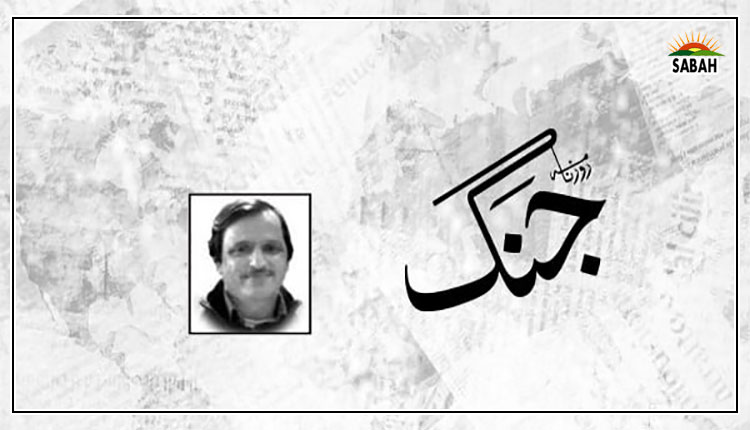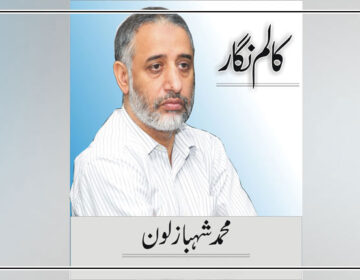ایک وقت ایسا بھی تھا جب بلوچستان میں اخبار، رسائل یہاں تک کے پرنٹنگ پریس، لگانے پر بھی پابندی تھی۔ بقول ایک دانشور کے ’’میرے والد کو ایک بار اخبار پڑھنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا‘‘۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ صرف ’غیر سیاسی‘ خبروں کی اجازت ملی۔ آج اخبارات بھی ہیں، ٹی وی بھی اور ڈیجیٹل میڈیا بھی مگر پھربھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اصل بلوچستان کہیں ’لاپتہ‘ ہو گیا ہے اور اسی بلوچستان کی تلاش میں پچھلے ہفتہ کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ اندازہ ہوا کہ کیا کیا ’مسنگ‘ ہے مگر جس بات نے حوصلہ اور امید دی وہ ہےوہاں کا نوجوان اور اسکے ’سوالات‘ جنکے جوابات آسان نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے وہاں کی انتظامیہ نے ’کوئٹہ پریس کلب‘ کو سیل کر دیا کیونکہ وہاں ایک سیمینار کا انعقاد ہونا تھا جس سے دیگر مقررین کے علاوہ بقول ایک سینئر صحافی ’ماہ رنگ بلوچ‘نے بھی خطاب کرنا تھا۔ شاید سیمینار کی خبر اتنی بڑی نہ بنتی جتنی کلب کی تالہ بندی کی خبر بنی۔
تاریخ سے سبق سیکھنے کی ہمیں مجموعی طور پر عادت نہیں ورنہ وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی اور انکے دوستوں جن میں سے کچھ کا تعلق ایک وقت میں صحافت سے بھی رہا ہے کویہ تو پتا ہی ہوتا کہ جبر، پابندیاں اور سنسرشپ ہمیشہ مزاحمت کو جنم دیتی ہے جس کا سب سے موثر ذریعہ لٹریچر ہے اور یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں تربت میں ایک کتابی میلے میں ’ریکارڈ سیل‘ہوئی۔ مزاحمتی ادب و شاعری وہاں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں اور ’کوئٹہ لٹریچر فیسٹیول‘ میں ’بلوچستان قومی میڈیا کی نظر میں‘ کے سیشن میں مقررین نے اس پر مکمل اتفاق کیا کہ قومی میڈیا بلوچستان کو نظرانداز کرتا ہے۔ بات صرف ایک صوبہ کی نہیں بلکہ ہمارے مجموعی صحافتی زوال کی ہے۔ ہماری صحافت محض ’بیانات‘ کے گرد گھومتی ہے۔ اب تصور کریں کہ یہ بھی برداشت نہیں، تو یہ کیسے برداشت ہوگا اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس ساری صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان میں پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ صحافی بلوچستان میں شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ وکیل بھی یہیں شہید ہوئے، یہاں کے صحافیوں کو خاص طور پر 9/11 کے بعد جس دباؤ کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اخبار میں کام کرنے والے رپورٹر اور ڈیسک پر چاروں جانب سے پریشر ہوتا تھا ’خبر‘ نہ دینے پر انہیں خود خبر بنا دیا جاتا تھا اور اگر خبر دیں تو دوسری طرف سے کبھی اشتہار بند تو کبھی صحافی بند یا لاپتہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک گروپ یہاں تک بتاتا تھا کہ ’خبر‘ یا ان کا بیان کس صفحہ پر اور کتنے کالم لگانا ہے۔ جب مدیران مجبوراً ایسا کرنے لگے تو انتظامیہ نے 12 اخبارات اور ان کے مدیران کیخلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرلیے۔ بدقسمتی سے صحافیوں اور مدیران کی اس تشویش پر توجہ ہی نہ دی گئی کہ اگر وہ کالعدم تنظیموں کے بیانات نہیں دیں گے تو انہیں جان خطرہ ہے اور ایسے واقعات ہو چکے تھے اور فیصلہ انکے خلاف آیا ، اب تک پچاس سے زائد صحافی نشانہ بن چکے ہیں۔
میں اپنے عہد کے مشہور شاعر جن کا تعلق اسی صوبہ سے تھا اور زمانہ طالبعلمی کے ساتھ حاصل بزنجو کے ’بلوچستان‘ کو تلاش کرنے گیا تھا۔ میں نے اور حاصل نے جامعہ کراچی میں بڑا وقت ساتھ گزارا ہے اور میں ان چند دوستوں میں سے ہوں جن کو اس نے سب سے پہلے اپنی مہلک بیماری کا بتایا تھا۔ وہ اپنے والد جن کو ’بابائے بلوچستان‘ بھی کہا جاتا تھا میر غوث بخش بزنجو کی طرح ٹھنڈے مزاج کا تھا مگر وہ اس دن پھٹ پڑا جب سینیٹ میں واضح اکثریت کے باوجود اسے ہماری ریاستی اشرافیہ نے ہروا دیا اور بدقسمتی دیکھیں کہ اس وقت ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے اسے ’سینیٹرز کے ضمیر‘ کی آواز کہا حالانکہ بقول حاصل وہ ’فیض حمید‘ کی آواز تھی جیسا کہ ایک زمانے میں ضمیر کی آواز دراصل ’احتشام ضمیر‘ کی آواز ہوتی تھی۔
جس بات نے مجھے حوصلہ دیا وہ وہاں کےبلوچ، پشتون، ہزارہ نوجوانوںاور ایک نئی اصطلاح جو وہاں استعمال ہوئی ’’Settlers‘‘کے درمیان یکجہتی اور ایک لبرل ماحول میں گفتگو اور سوالات کا معیار تھا جو انکے سیاسی شعور کو اجاگر کر رہا تھا مثلاً ایک غالباً اسکول کی بچی نے ایک مہمان سے سوال کیا ’’سر میں آپ کو سوشل میڈیا پر فالو کرتی ہوں آپ بتائیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔‘‘ مہمان نے جواب دیا ’’بیٹا تمہارا یہ سوال ہی اس عمر میں زندگی کی علامت ہے۔‘‘ ایک انتہائی گہرا سوال ایک یونیورسٹی کی لڑکی نے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی سے کیا ’’یہ بتائیں کہ آخر کچھ لوگ آزادی کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں انکے سوالات کا کیا جواب ہے۔‘‘ سرفراز جس حد تک جواب دے سکتے تھے انہوں نے دیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہر ماہ اس جامعہ میں طلبہ و طالبات سے ایک دو گھنٹے تبادلہ خیال کریںگے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ کرسکتے ہیں تو کوئٹہ پریس کلب سیمینار کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ وہ کتنے ’بااختیار‘ ہیں مگر کلب کو ایک سرکاری افسر کا تالہ لگانا اس بات کا غماز ہے کہ ہمیں تنقید برداشت نہیں۔ بہرحال مجھے ’لاپتہ بلوچستان‘ مل گیا اور وہ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں موجود ہے جو سوال کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ مگر ابھی بہت کچھ لاپتہ ہے، خود صوبائی وزیرتعلیم راحیلہ درانی کہتی ہیں کہ یہاں کے لاکھوں بچے اسکول نہیں جاتے ۔ ایسے بچے انتہا پسندوں کے بھی ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ صحت کا حال تو ایک خاتون نے ہمیں کراچی ائیرپورٹ پر ہی بتا دیا وہ میرے اور انور مقصود کے پاس آئی اور کہنے لگی ’’انور صاحب، میں کوئٹہ کی شہری ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے ہر مہینہ مجھے یہاں آنا پڑتاہے۔ ایک اچھا معیاری اسپتال تک نہیں ہے کوئٹہ میں باقی صوبے کا حال تو ناہی پوچھیں‘‘ ۔
یقین جانیں کوئٹہ ایسا نہیں تھا، کبھی ہم نے اسے سیاست کی نذر کر دیا تو کبھی ریاست کی نذر۔ یاد رکھیں، کبھی کسی غیر مقامی کو صوبہ سے نکالنے سے اصل مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ ہی گورنرراج یا فوجی آپریشن سے چاہے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، جنرل مشرف کے زمانے میں یا اس کے بعد۔ کیا اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ معاملہ سوئی گیس کا ہو یاریکوڈک کا یا گوادر پورٹ کا کسی بھی زمین کے پہلے حقدار اس کے مکین ہوتے ہیں۔ جس طرح پورے ملک میں جاگیرداری نظام نے جمہوریت کی جڑ یںمضبوط نہیں ہونے دیں اسی طرح سرداری نظام بھی ہماری ریاستی اشرافیہ کا کاسہ لیس رہا۔ مگر اب معاملہ ان کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ جانے سے پہلے کچھ دوستوں نے کہا ’حالات ٹھیک نہیں ہیں نہ جائیں۔ میں نے کہا صحافی تو جاتا ہی اس جگہ ہے جہاں سے دوسرے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں یاجاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ویسے ان تین دنوں میں یقین جانیں مجھے ایک روز بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میرا ’موبائل‘ گن پوائنٹ پر چھین لیا جائے گا۔ ایک ڈرائیور سے میں نے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا ’’سر یہاں موبائل نہیں بندہ غائب ہوتا ہے‘‘۔
بشکریہ روزنامہ جنگ