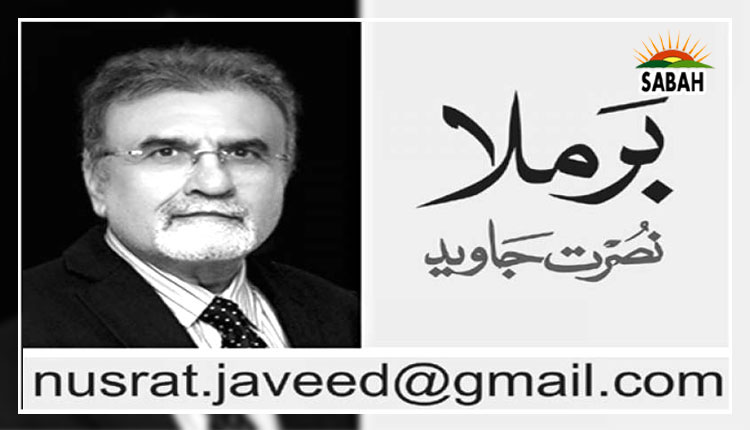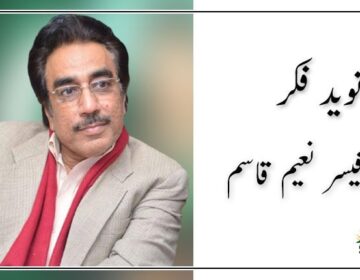ملکی سیاست پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بنیادی طورپر رزق کمانے کے لئے ہفتے کے پانچ دن اس کالم کے ذریعے تبصرہ آرائی کی مشقت میری مجبوری ہے۔ یہ مجبوری اکثر مجھے اب قوم یاجوج ماجوج کی یاددلانا شروع ہوگئی ہے۔ قوم یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے تو ذہن میں برجستہ یہ سوال امڈ آیا کہ ہماری نوجوان نسل کا کتنے فی صد اس قوم پر مسلط ہوئے عذاب سے واقف ہے۔ اگر ان کی اکثریت قوم یا جوج ماجوج سے آگاہ نہیں تو میرے کرب کا اندازہ نہیں لگاپائے گی۔ وہ نسل جس نے بقول اقبال ستاروں پر کمند ڈالتے ہوئے وطن عزیز کو مجھ جیسے بڈھوں کے خیالات سے نجات دلانا ہے اس حقیقت سے واقف نہیں کہ روایتی صحافت کتنا صبر طلب دھندا ہے۔
نوجوانوں کی بے پناہ اکثریت بالخصوص ان میں سے وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے بھرپور استعمال کے ذریعے ہماری ذہن سازی میں مصروف رہتے ہیں نہایت حقارت سے یہ طے کربیٹھے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ایجاد سے قبل اخبارات کے ذریعے جو صحافت ہوا کرتی تھی اسے حکمرانوں کے منشی ہوئے لفافے چلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 24/7چینل آئے تو لفظ فروش سوٹ ٹائی اور سرخی پاؤڈر لگاکر ٹی وی سکرینوں پر نمودار ہونے لگے۔ لاکھوں میں تنخواہیں لیتے اور مزے کی زندگی گزارتے۔ بالآخر عمران خان کی صورت ایک دیدہ ور رونما ہوا تو لفافے بے نقاب ہونا شروع ہوگئے۔ ویسے اب موبائل فون کا ہر مالک جب چاہے صحافی کا فریضہ سرانجام دے سکتا ہے۔ یہ دھندا چند لوگوں تک محدود نہیں رہا۔
ٹھنڈے دل سے اگر سوچیں تو ماننا پڑے گا کہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے جب چاہے چند کلمات یا کوئی تصویر فیس بک وغیرہ پر لگاکر صحافی سے مختص فرض نبھاسکتا ہے۔ اس بارے میں غور کرتے ہوئے مگر ذہن میں فوری خیال یہ بھی آیا ہے کہ تھوڑی محنت وکوشش سے کوئی بھی صحت مند شخص بکرے کوذبح کرسکتا ہے۔ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد مگر اس کی بوٹیاں بنانا ہوتی ہیں۔ بوٹیاں بنانا ایک ہنر ہے۔ یہ ہنر مجھے لاہور سے اسلام آباد منتقل ہونے کے بعد ہر دوسرے دن یادآتا تھا۔ سوچتا تھا کہ شاید میں پہاڑوں میں خود روگھاس کھاتے بکروں کے گوشت کے ذائقے سے لطف اندوز نہیں ہوسکتا۔پنجاب کے میدانوں میں پلے جانوروں کا گوشت کھانے کی عادت پک چکی تھی۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک باذوق گوشت خور نے سمجھادیا کہ اسلام آباد کی دوکانوں میں بکتا گوشت اناڑی ہاتھوں سے کٹا ہوتا ہے۔ بوٹی کاٹنے کا ایک خاص طریقہ ہے جہاں رگوں کو الٹی سمت سے کاٹنا فن کاری نہیں اجڈ پن ہے۔ موبائل فون کی بدولت ہوئی صحافت جسے سیٹیزن جرنلزم کا رومانوی نام دیا گیا ہے درحقیقت عطائی کے ہاتھوں کاٹی بوٹی ہے۔
کالم لکھنے کے لئے جب قلم اٹھایا تھا تو ذہن میں ایک سنجیدہ موضوع تھا۔ روانی میں گوشت کاٹنے کے ہنر کی جانب بہک گیا۔ دو صدی قبل انگریزی نثر لکھنے والوں نے یورپی ادب سے ایک طرز مستعار لی تھی۔ اسے Stream of Consciousness کہا جاتا تھا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ وہ طرز تحریر ہے جس میں خیالات کو منطقی انداز میں ایک کے بعد دوسرے لفظ یا تصور سے کوئی ٹھوس پیغام دینے کے لئے لکھا نہیں جاتا۔ قلم اٹھاتے ہی جو خیال ذہن میں آئے اس سے شروع ہوں اور درمیان میں یہاں وہاں بھٹکنے سے گریز نہ کریں۔ عام دنوں میں ہم دن کے 24گھنٹے فقط ایک ہی موضوع پر توجہ مرکوز نہیں رکھتے۔ ہر نوع کے خیالات ذہن میں مسلسل امڈتے رہتے ہیں۔ جس طرز تحریر کا میں ذکر کررہا ہوں اس کا اظہار سنا ہے قر العین حیدر کی ابتدائی تحریروں میں بہت نمایاں تھا۔ اسی باعث ان کا بہت مذاق بھی اڑایا گیا۔ جس زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا ان دنوں مقصدی ادب کا بہت چرچہ تھا اور وہ اس سے گریز کی مجرم ٹھہرائی گئیں۔
اردو ادب کے کلاسیکی لکھاری مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرجانے اور 1857 کی ابتری سے بوکھلاکر ماضی کی یادوں سے سہارا تلاش کرنا شروع ہوگئے تھے۔ غالب نے ہائے دلی وائے دلی،بھاڑ میں گئی دلی کا نوحہ پڑھتے ہوئے بھی سرسید احمد خان جیسے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ آثار الصنادید جیسی کتابیں لکھتے ہوئے ماضی کی میراث پر ماتم کنائی سے گریز کریں۔ ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سرسید ایک دوسری انتہا کو چلے گئے تو اکبر الہ آبادی جیسے شاعروں کی طنز کا نشانہ ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد جیسے لکھاریوں نے اصلاحی ناولوں سے اپنی تہذیب بچانے کی کوشش کی۔
انگریز کا مسلط کردہ نظام مگر جب مستحکم ہوگیا توترقی پسند ادب کی تحریر شروع ہوگئی جس نے ادب میں مقصدیت کا تقاضہ کیا۔ مذکورہ تحریک سے کہیں بالا اقبال کی صورت ایک شاعر ابھرے جنہیں کسی ایک خاص طرز یا سوچ سے مختص کرنا ناممکن ہے۔ وہ مسجد قرطبہ کا شکوہ یاد دلاتے ہوئے لینن کو خدا کے حضور بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی مسولینی سے ایک ملاقات کا ذکر بھی ہے۔ میں جاہل فقط یہ فرض ہی کرسکتا ہوں کہ ان کی بے پناہ متجسس طبیعت گزری صدی کے آغاز میں چلی تمام سیاسی وفکری تحاریک پر نہایت خلوص سے غور کرتی رہی۔ چند مجاور ذہنوں نے مگر ان کی سوچ کو محدود تر بناکر ان کے ساتھ ہی نہیں ہماری اور ہمارے بعد کی نسلوں پر بھی ظلم کیا ہے۔
ارتکاز فکر سے محروم ذہن کالم کے اختتام تک پہنچ گیا ہے۔ آپ میں سے چند لوگوں نے اگر یہاں تک پڑھنے کی ہمت وحوصلہ برقرار کھا ہے تو آج کے کالم میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ریاست کے مبینہ طورپر تین ستون ہوتے ہیں۔ انتظامیہ،عدلیہ اور پارلیمان ان کے نام ہیں۔پارلیمان تو عرصہ ہوا اپنا وقار کھوچکی ہے۔ باقی رہ گئے تھے دو ستون۔ ان دوکے مابین اب ایک دوسرے کو نیچادکھانے کی گیم شروع ہوچکی ہے۔ ملکی سیاست کا دیرینہ شاہد ہوتے ہوئے نہایت ڈھٹائی سے اصرار کررہا ہوں کہ دو ستونوں کے مابین جو چپقلش جاری ہے مقصد اس کا میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی کے حقیقی دکھوں کا مداوا نہیں۔ اشرافیہ کے مابین زیادہ سے زیادہ اختیارات کے حصول کی ہوس ہے۔
ان کے اوپر کھڑے حکومتی اور ریاستی ڈھانچے کو ہچکولے دینا شروع کر دئیے ہیں۔ اسی باعث اس ڈھانچے کے محصور ہوئے مجھ جیسے افراد کے اذہان اب چکرانا شروع ہوگئے ہیں اور آج کے کالم کی بے ربطی اس کا واضح اظہار ہے۔
بشکریہ روزنامہ نوائے وقت