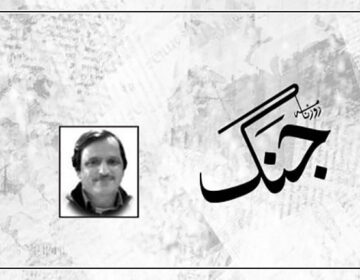تضادستان کے حالات دیکھ کر ہندوستان میں مشرقی تمدن کے آخری نمونے لکھنو کی یاد آتی ہے۔ ماضی کےلکھنو کی سرگزشت پڑھیں تو وہاں کے نواب، انکے حرم، انکے چسکے دار کھانے، رنگ برنگے لباس، مٹیابرج اور دوسری شاندار عمارتیں اور محل، وہاں کی جذباتی اور بھڑکیلی شاعری یاد آ تی ہے۔
اس زوال پذیر تہذیب میں میر انیس اور میر دبیر نے مرثیے کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ۔ افسوس کہ تضادستان میں نواب واجد علی خان جیسی عیاشیاں کرنے والے اشرافیہ کے لوگ تو جا بجا نظر آتے ہیں لیکن ریاست کی کمزوری اور زوال کو بیان کرنے والا میر انیس ایک بھی نہیں۔
آپ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں دیکھیں سب سے زیادہ رش کھانوں کی دکانوں پر ہے، لائبریریاں اور میوزیم بھاں بھاں کر رہے ہیں ۔جس طرح لکھنو کا نظام حکومت مفلوج ہو چکا تھا وہی حال تضادستان کا ہے۔
ہندوستان میں اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا غالب لکھنو گئے تو کسی نے گھاس تک نہ ڈالی وہ مایوس واپس دلی لوٹ گئے، نواب واجد علی خان نے بعداز خرابی بسیار 500روپے سالانہ وظیفہ مقرر تو کیا مگر تب تک غالب دلی میں ہی رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔
تضادستان میں بھی ٹیلنٹ کی کوئی پہچان نہیں، یہاں امید مرتی جا رہی ہے ریاست کے حکمران اور سیاست دان امید کو جگائے رکھتے ہیں لیکن یہاں کسی کو مستقبل کی فکر ہی نہیں۔
یہ کالم نگار ساری زندگی رجائیت پرست رہا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ بالآخر تضادستان میں بھی مثبت تبدیلی آ ئے گی اور ہم خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف روانہ ہونگے ۔
فرض کریں کوئی کسی حقیقت پسند سے یہ سوال پوچھے کہ پانچ سال بعد تضادستان کہاں کھڑا ہوگا تو وہ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے فیض احمد فیض کا یہ فقرہ دہرائے گا کہ ڈر ہے یہاں کےحالات اسی طرح کے ہی رہیں گے اور اگر کسی قنوطی سے یہ سوال پوچھا جائے تو جھٹ جواب دے گا، یہاں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، یہاں کی معیشت کے ٹھیک ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔
ان آراء کے بعد تضادستان کی زمینی صورتحال سن لیں۔ تضادستان کے سب سے بڑے صنعتی گروپ جو اب ملٹی نیشنل ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ اسکے سربراہ کے 4 پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں میں سے کوئی ایک بھی اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں، یہ خاندان یہاں کی اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، مال و دولت، عزت، شہرت اور ساکھ سب ان کو حاصل ہے لیکن سارے بچے امریکہ اور یورپ میں مقیم ہیں اور ان میں سے کوئی واپس آکر اتنا بڑا کاروبار سنبھالنے کو بھی تیار نہیں۔
اسی طرح کے اور صنعتی خاندان جس کی ایک زمانے میں سب سے بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری ہوا کرتی تھی وہ سارا خاندان بیرون ملک شفٹ ہو چکا ہے، کاروبار یہاں چل رہے ہیں مگر وہ تضادستان میں رہنے کو تیار نہیں۔
کتنے ہی خاندانوں کو ہم جانتے ہیں جو دبئی اور بیرون ملک بیٹھ کر کاروبار چلاتے ہیں، لاکھوں افراد بیرون ملک جاکر مقیم ہوگئے۔ جو بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں ان کیلئے یہاں مواقع نہیں اس لئے وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں اور تو اور ملک ریاض، جو حکمران اشرافیہ کو ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے ہیں، بھی کئی سال سے بیرون ملک مقیم ہیں۔
سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے اور اسے روکا نہ گیا تو تضادستان میں رہ کیا جائےگا؟
گزشتہ لکھنو میں ’’تماشا اور تماشا گری اساسی کردار رکھتی تھی کہا جاتا ہے کہ لکھنوی کلچر میں سمندر جیسی گہرائی نہ تھی یہ بند معاشرے کے جوہڑ جیسا کلچر تھا، یہ انحطاط کا کلچر تھا‘‘
آج کے تضادستان کی سڑکوں اور پارلیمان میں ہونے والی گفتگو کیا کسی تماشے سے کم ہے؟ جس معاشرے میں عورتوں اور اقلیتوں کو گھیر گھار کر نشانہ بنایا جاتا ہو وہ زوال پذیر معاشرہ ہی ہوتا ہے۔
لکھنو میں سطحی جذباتیت کی فراوانی تھی یہی حال تضادستان کا ہے، حالیہ الیکشن میں لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا لیکن نہ کسی نے سیاسی جماعتوں کے منشور پر توجہ دی نہ کسی جماعت کی ماضی کی کارکردگی پر بحث مباحثہ ہوا اورنہ ہی مستقبل کے منصوبوں پر کوئی لے دے ہوئی، ایک طرف تحریک انصاف کے جذباتی ووٹر نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو دوسری طرف نون کے ووٹر اور سپورٹر کا انداز بھی جذباتی ہی تھا نہ سیاست میں منطقی انداز ہے نہ معاشرت اور نہ معیشت میں۔
نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کوئی بھی قومی معاملہ سلجھ نہیں رہا بلکہ ہمہ جہت الجھاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
توقع تھی کہ انتخابات کے بعد ماحول بدلے گا مگر فضا اور بھی مسموم ہوتی جا رہی ہے سچ لکھیں تو ایک جماعت گالیوں پر اتر آتی ہے، دوسری جماعت کہتی ہے یہ فلاں کا حامی بن گیا ہے اور طاقتور سمجھتے ہیں کہ یہ پٹڑی سے اتر رہا ہےاسے دوبارہ پٹڑی پر چڑھایا جائے، جب معاشرہ اس طرح کی تقسیم کا شکار ہو جائے تو یہ زوال کی طرف بڑھنے کی نشانی ہی ہوتی ہے۔
آج کی جدید دنیا میں ریاست کو مثبت رخ دینے کی سب سے زیادہ ذمہ داری سیاست دانوں کی ہوتی ہے پاکستانی عوام نے ووٹ دیکر سیاست دانوں کو اختیار دے دیا ہے کہ ریاست اور عوام کی تقدیر کا فیصلہ وہ کریں، اب اگر یہ سیاست اناپرستی اور اقتدار پرستی کے پنجروں میں بند رہی تو یہ قوم بھی اسیر ہی رہے گی، اسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوگی، کاش کوئی ایک فریق صرف پانچ سال کے اقتدار کی قربانی دیدے تو معاملات مثبت رخ اختیار کر سکتےہیں مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟
برصغیر اور خاص طور پر اس کے شمالی خطے کے باشندوں میں ایک جنیاتی خرابی ہے کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑے، فساد اور قضیے حل نہیں کر پاتے، ہمارے ہاں بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ برسوں چلتا ہے۔ عدالتوں میں 70سے 80 فیصد مقدمات قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں۔
صوبوں، شہروں، ذاتوں، برادریوں، شوہروں اور بیویوں کے درمیان تضادات کے حل کا ہم آج تک کوئی طریقہ دریافت نہیں کرسکے، ساس اور بہو کا معاملہ آج بھی ہر خاندان کا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کا کوئی سماجی اور معاشرتی حل ہم نہیں نکال سکے۔
مغربی معاشروں نے اپنے تضادات، لڑائیوں اور جھگڑوں کو حل کرنے کے منطقی طریقے اپنائے وہاں اب ساس بہو کے اکٹھے رہنے کا کلچر ہی نہیں ہے ماں باپ کو سنبھالنا بیٹے اور بہو کی ذمہ داری نہیں بلکہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، ہوسکتا ہے کہ یہ حل غلط ہو مگر کم از کم ان معاشروں نے مسائل کے حل کی طرف توجہ دی اورترقی کی منزل پالی۔
ہمیں بھی دنیا سے سیکھ کر اپنے سیاسی اور سماجی مسائل کا حل نکالنا چاہئے ہوسکتا ہے کہ یہ حل ٹھیک نہ ہوں، ان پر پھر سوچا جائے اور پائیدار حل کی طرف بڑھا جائے لیکن یہ طریقہ کہ ہم نے کسی مسئلہ کو حل نہیں کرنا دراصل زوال کی طرف لے جاتا ہے۔
آج ہم جس موڑ پر آگئے ہیں اس کے بعد گہری کھائی ہے۔ اگر ہم لکھنو والی جذباتیت پر ہی گامزن رہے تو پھر کوئی ہمیں گرنے سے روک نہیں سکے گا۔
اگر ہم آج بھی منطقی انداز میں سیاست اور معاشرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل نکالنے میں یکسو ہو جائیں تو ہمارا زوال رک جائے گا اور ہوسکتا ہے اس کے بعد ہمارا عروج کی طرف سفر شروع ہو جائے۔
بشکریہ روزنامہ جنگ