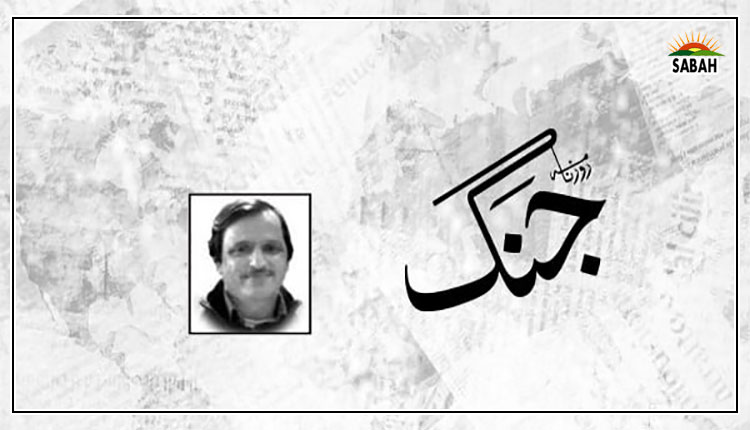16دسمبر2014پشاور میں بلا کی سردی تھی،شدید دھند چھائی ہوئی تھی۔ سورج منہ چھپائے بیٹھا تھا شائد قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھنے کی سکت اس میں بھی نہیں تھی۔ بچے گرم بستر میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے جگایا تو سونو نے نیند بھری آواز میں کہا امی آج نہیں جانا اسکول، آج چھٹی کر لیتا ہوں۔ میں نے زور دیتے ہوئے کہا آج چلے جاؤ بیٹا پھر تو چھٹیاں آ رہی ہیں۔ خوب مزے کرنامیں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود ہی مقتل کی طرف روانہ کر دیا۔ میرا چھوٹا بیٹا اکثر کہتا تھا امی اس کا نام اسفند ہے اتنا سونو کہیں گی تو لوگ اسفند کو بھول جائیں گے۔ مگر سونو کہتا تھا امی آپ جتنی بار جی چاہےکہیں، اسکی نہ سنیں۔‘‘
’’جب اس کی شہادت کی خبر آئی تو ذہن ماؤف ہو چکا تھا مگر دل میں امید تھی کہ شاید وہ زخمیوں میں مل جائے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اسے لاشوں میں تلاش کرنا پڑے گا۔ کئی لاشیں دیکھنے کے بعد سونو کی لاش مل گئی۔ اس کا ایک جوتا سفید چادر کے اوپر رکھا تھا۔ اسکول کارڈ جس میں اس کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی اوپر رکھا تھا، اس کے سر پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور گلے میں ٹائی جلد کے ساتھ سلی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مجھ سے مخاطب تھی جیسے کہہ رہا ہو دیکھیںامی یہاں اسفند لکھا ہے…. سونو چلا گیا‘‘۔
ان جذبات کا اظہار اسفند یا سونو کی والدہ نے حال ہی میں کراچی کی ایک ٹیچر محترمہ عظمیٰ علی اختر کی کتاب ’’میرا یقین‘‘ میں کیاہے۔ ان کے اور کوئی22سے زیادہ والدین کے اپنے بچوں کے بارے میں اس سیاہ دن کے حوالے سے جذبات پڑھ کر دل دہل سا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے آرمی پبلک اسکول پشاور کی جب دہشت گردوں نے سو سے زائد بچوں اور وہاں موجود ٹیچرز کو بے دردی سے شہید کیا۔ یہ مقابلہ تھا علم کا جہالت سے، اندھیروں کا روشنی سے۔ علم کے ہاتھ میں کتاب اور قلم تھا اور جہالت کے ہاتھ میں اسلحہ، روشنی مستقبل کے معماروں کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی اور اندھیرا حملہ آوروں کے چہروں سے عیاں تھا۔ ان بچوں نے مر کر بھی علم کے چراغ روشن کیے اور امر ہو گئے، دہشت گرد اس روشنی کو پھیلنے سےنہ روک سکے۔
آج اس واقعہ کو گزرے 10سال ہو گئے ہیں شہید ہونے والے ہر بچے کی ماں کی کہانی ایک جیسی ہی لگتی ہے کچھ نے تو دو دو بیٹوں کو کھویا۔ کسی کے دو میں سے ایک شہید ہوا،ایک زخمی۔ ایک والدہ نے اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کتاب میںلکھا ’’اسامہ اور حسن دونوں میرے لخت جگر تھے اور اس دن دونوں ہی اسکول کے اس آڈیٹوریم میں موجود تھے۔حسن کے نصیب میں جو چھوٹا تھا زندگی آئی اوراسامہ نے حیات ابدی پائی۔ حسن کی کیپ سے گولی گزر کر پارہو گئی تھی او روہ زخمی تھا اسامہ کی تلاش جاری تھی۔ شام کے قریب ایمبولینس آ کر رکی۔ اسامہ کی میت صحن میں چارپائی پر رکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں چوری کی پلیٹ تھی جس کے چند نوالے وہ صبح کھا کر گیا تھا کہ امی واپس آ کر باقی کھا لوں گا۔ میں بے اختیار سیڑھیاں اتر رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میرا بیٹا آ گیا۔ اسامہ بیٹا چوری کھا لو…. آنکھیں کھولو لیکن وہ خوبصورت آنکھیں اس دنیا کے منظر کو اب نہیں دیکھ پا رہی تھیں‘‘۔صائمہ زریں جو استادتھیں ،کی جڑواں بہن نے اپنے جذبات کچھ اس طرح بیان کیے ’’ اس دن اس کا اپنے اسکول میں ایک ماہ مکمل ہوا تھا۔ اپنی شادی کے بعد وہ پہلے منگلا منتقل ہو گئی تھی پھر جب شوہر کا تبادلہ پشاور ہوا تو اس نے APS میں ملازمت کر لی۔ میں نے اور اس نے ایم اے ساتھ مکمل کرنے کے بعد ایم فل ، پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تھا۔ اسکول میں اس دن تقریب تقسیم ِ اسناد تھی اور وہ اس ہال میں موجود تھا جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا ۔ جس بچے کی جان اس نے بچائی اس نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ کس طرح صائمہ نے کئی بچوں کو اپنی آغوش میں لیا وہ گولیاں کھاتی رہی اس بچے کی ٹانگ پر گولی لگی مگر وہ بچ گیا‘‘۔
ایمن خان سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ اس کی ماں کے بقول اس کی منگنی اپنی خالہ زاد سے کر دی تھی۔ ’’کس ماں کا ارمان نہیں ہوتا کہ بیٹے کا سہرا دیکھے۔ زندگی میں جو کچھ سوچا تھا نہیں ہوا لیکن اس درجہ برا ہو جائے گا یہ تصورمیں بھی نہ تھا۔‘‘
یہ داستان کرب ہے دو سگے بھائی ذیشان اور اویس کی۔ ان کی والدہ لکھتی ہیں ’’جس گھر سے دو بیٹوں کے جنازے اٹھیں وہاں کہرام برپا ہوتاہے۔ ہمارا گھر بھی اس حال میں تھا ۔ان کی آوازیں، باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ آج بھی ان کا منتظر ہے۔
اب نہیں لوٹ کے آنے والے
گھر کھلا چھوڑ کےجانے والے
دنیا کیلئے یہ جنگ 9/11 کے بعد شروع ہوئی مگر پاکستان اس کا شکار 80کی دہائی سے ہے اور اگر غور کریں تو لاکھوں خاندان اجڑ گئے۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہماری اپنی ناقص پالیسیوں کے باعث، نوجوان ڈرگ اور اسلحہ مافیا کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ملک فرقہ واریت، لسانیت اور جہالت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نا جانے کتنے لوگ ، نوجوان لا پتہ ہو گئے ۔ پاکستان جو کبھی ایک محفوظ ملک تصور کیا جاتا تھا غیر محفوظ ہو گیا۔ جس معاشرےمیں شاعر لاپتہ اور صحافی قتل کر دیا جائے وہاں کبھی نوجوان مشال خان انتہا پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو کبھی بے نظیر بھٹو جیسی اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم شہید کر دی جاتی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے شہدائے پاکستان کی اور ہرشعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی ۔کس کس کی کہانی پیش کی جائے مگر کیا بدنصیبی ہے ہماری کہ بڑے سیاسی مخالفین بھی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے تو اس وقت جب بچے شہید ہو گئے۔ ایک نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا کہ ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ آج اس بات کو بھی 10سال گزر چکے ہیں۔ انتہا پسندی اپنے عروج پر ہےاور یہ وہ پودا ہے جو اب درخت بن چکا ہے اور حکومت و ریاست اب تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ انتہا پسندی ہوتی کیا ہے۔
سچ پوچھیں تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ دہشت گردوں نے اسکولوں کودھماکوں سے اڑا دیا تو کبھی ہماری بچیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی ۔ہم نے بڑی جنگ کا آغاز کیا پھر بھی 16دسمبر2014ہو ہی گیا۔ کیا دن ہے یہ ہماری تاریخ کا! کبھی 1971 کو سیاہ دن کہتے ہیں کبھی 2014کو۔ 1971نہ ہوتا تو شائد 2014بھی نہ ہوتا۔ بقول شہیر خان کی والدہ ’’زندگی بھی کیسے صفحات چھپا رکھتی ہے۔ اپنے جگر گوشے کی خون میں ڈوبی لاش میں نے دیکھنا تھی۔ ایک بار اس کے کالر پر خون کا دھبہ کسی جھگڑے کے نتیجے میں آ گیا تھا تو اس نے واش روم میں جا کر دھو دیا کہ میں نہ دیکھ لوں۔ نہ اسے پتا تھا نہ مجھے کہ آئندہ زندگی کے صفحات اس کے خون سے رنگین ہونگے جو کبھی دھل نا پائیں گے۔
کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار
خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد
بشکریہ روزنامہ جنگ