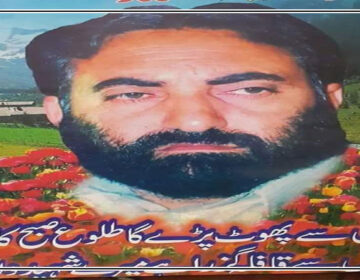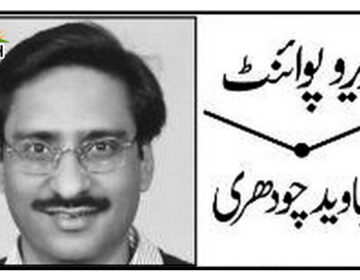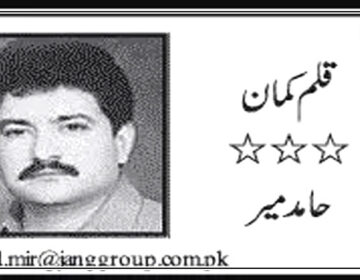28 جنوری 1965کی ایک سرد شام تھی۔ گلبرگ کے ایک بنگلے سے دو افراد برآمد ہوئے اور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ستاون برس قبل گلبرگ لاہور کے نواح میں اشرافیہ کی کسی قدر غیرآباد سی بستی تھی۔ یہ عوامی لیگ کے صوبائی رہنما ملک غلام جیلانی کا گھر تھا اور ان کے دونوں مہمانوں میں ایک مغربی پاکستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے بے باک رکن عبدالباقی بلوچ اور دوسرے لاہور کے معروف صحافی ضمیر قریشی تھے۔ اچانک کچھ نامعلوم افراد نے گاڑی پر گولیوں کی بارش کر دی۔ اس قاتلانہ حملے میں باقی بلوچ شدید زخمی ہوئے اور ضمیر قریشی جاں بحق ہو گئے۔ یہ پاکستان میں کسی صحافی کا پہلا قتل تھا اور مرنے والے کا نام ضمیر تھا۔ یہ اس حقیقت کا دل گداز اشارہ تھا کہ صحافی کا قتل اجتماعی ضمیر کا قتل ہے۔ اس کے بعد یہ نامبارک روایت پھیلتی ہی چلی گئی۔
اشاعتی پابندیوں اور قید و بند کا سلسلہ تو اکتوبر 1949 کے اس پبلک سیفٹی ایکٹ ہی سے شروع ہو گیا تھا جس پر بابائے قوم نے بطور گورنر جنرل دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اغوا، سرعام تشدد اور گاہے گاہے قتل بھی صحافتی منظر کا حصہ بنتے گئے۔ ایک تاریک زمانہ ایسا بھی آیا کہ صحافیوں کی پشت پر کوڑے تک برسائے گئے۔ صحافت کو ریاستی جبر کی ان صورتوں سے کہیں زیادہ نقصان صحافی کے قلم کی خرید و فروخت سے پہنچا۔ صحافت کی ساکھ ہی اس اصول سے قائم ہوتی ہے کہ صحافی قومی اور عوامی اہمیت کے کسی مسئلے پر اختلاف یا اتفاق کا حق تو رکھتا ہے لیکن وہ ریاستی منصب یا عوامی عہدے کا طلبگار نہیں ہوتا۔ صحافی کے لئے سیاسی رائے سے مفر نہیں لیکن وہ سیاسی تقسیم میں فریق نہیں ہوتا۔ جنگ کے دوران بھی صحافیوں اور طبی عملے کے لئے اسی بنیاد پرتحفظ کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں گروہ تنازع سے قطع نظر محض اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرتے ہیں۔ ایک کا کام انسانی جان بچانا ہے اور دوسرے کا فرض عوام کو واقعات کی خبر دینا ہے۔ خبر سے محروم عوام اپنے حقوق سے آگہی رکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے مسائل کا درست تجزیہ کرسکتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ریاست اور حکومت میں حدِ فاصل کی ضرورت پیش آتی ہے۔
ہمارے دستور میں سرکاری اہلکاروں کے لئے سیاست میں حصہ لینے پر اسی لئے پابندی عائد کی گئی ہے کہ ریاست کی مستقل انتظامیہ اور عوام کی منتخب میعادی حکومت کے مفادات میں گٹھ جوڑ کا امکان ختم کیا جا سکے۔ آمریت کا بنیادی نشان یہی ہے کہ حکومت اور ریاست میں فرق مٹ جاتا ہے۔ بظاہر حکومت ریاست پر قابض معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل ریاست حکومت کے اختیارات سلب کر لیتی ہے۔ اس غبارآلود بندوبست میں عوام کے مفادات پس پشت چلے جاتے ہیں اور قوم کی تمدنی توانائی مفلوج ہو جاتی ہے۔ صحافت اپنی اساس میں ایک تمدنی خدمت ہے۔ آمریت یا تحکمانہ طرز حکومت کو صحافت اور اظہار کی آزادی سے خوف آتا ہے۔ ایسی حکومت خبر کا گلا گھونٹنے کے لئے محض صحافی پر دباؤ نہیں ڈالتی بلکہ اسے مفادات کا لالچ دے کر اپنی پیشہ ورانہ غیر جانبداری سے دست بردار ہونے پر بھی اکساتی ہے۔ ایسی جانبداری کو نظریاتی صحافت کا دلکش نام دیا جاتا ہے۔ اچھی صحافت نظریاتی نہیں ہوتی، دستور اور قانون کے دائرے میں اصولی موقف اختیار کرتی ہے۔ اصولی اور نظریاتی صحافت کا یہ باریک فرق محض اصطلاحات کا کھیل نہیں۔ یہ ایسا ہی جوہری فرق ہے جو نظریاتی اور جمہوری ریاست میں پایا جاتا ہے۔ جمہوری ریاست سیاسی نظریات میں جانبدار ہونے کی بجائے مختلف سیاسی مکاتب فکر کو مساوی دستوری تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نظریاتی ریاست قوم کے کسی ایک دھڑے کو ترجیحی درجہ دے کر پیوستہ مفادات کی آبیاری کرتی ہے۔ ٹھیک اسی نمونے پر نظریاتی صحافت مقبول عام نعروں کی آڑ میں یک طرفہ خبر اور تجزیے کی راہ اختیار کرتی ہے۔
ہمارے ملک میں نظریاتی صحافت کا عفریت 70ء کی انتخابی مہم میں نمودار ہوا۔ ایوب آمریت دباؤ اور ترغیب کے حربوں سے صحافت کو نیم جان کر چکی تھی۔ نوابزادہ شیر علی خان نے اس تیار زمین میں مذہب پسندی کا بیج بو دیا۔ بائیں بازو کی صحافت تو کبھی غیرجانبداری کی علمبردار نہیں تھی، اب دائیں بازو کے شہسوار بھی اس میدان میں اتر آئے۔ بھٹو صاحب پر جمہوریت، معیشت اور خارجہ معاملات میں دو رخی کا الزام دھرا جا سکتا ہے لیکن صحافت دشمنی میں وہ ایسے یکسو تھے کہ الطاف حسن قریشی اور حسین نقی میں امتیاز کے قائل نہیں تھے۔ جنرل ضیاالحق نے قومی تشخص کی ازسرنو تشکیل پر کمر باندھی تھی۔ اس نیک کام میں لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمٰن سے بہتر کارندہ میسر آنا مشکل تھا۔ اس ابتلا کو اب چار دہائیاں ہونے کو آئیں اور ہماری صحافت، محکمۂ مال کی اصطلاح میں ’بنجر، قدیم، ناممکن‘ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔
عدلیہ بحالی کی تحریک میں دیگر بہت سے مضمرات کے ساتھ ساتھ اہل صحافت کی کھلی جانبداری کا مظہر بھی شامل تھا۔ 2011ء میں اس سیلِ بلا کا رُخ ذرا سی سعی کے ذریعے تحریک انصاف کی حمایت میں بدل دیا گیا۔ نادیدہ ناخداؤں کی مصحف کا کون سا جزو تھا جسے شبانہ روز تکرار کی مدد سے اجتماعی حافظے پر مرتسم نہیں کیا گیا۔ مشکل مگر یہ ہے کہ سیاست ایک نامیاتی عمل ہے۔ جولائی 2018ء میں ’مثبت صحافت‘ کا درس حرز جان بنانے والے آج دوسرے کنارے پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ رائے عامہ مگر بجلی کا بٹن نہیں کہ انگلی کی جنبش سے ایک دہائی کی ذہن سازی متروک قرار پائے۔ مرحوم ارشد شریف کے بے رحم قتل کی واقعاتی جزیات ابھی سامنے آنا باقی ہیں مگر حقیقی سوال تو یہ ہے کہ ایک صحافی کو وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہ سوال اٹھانے کا حق انہیں ہی پہنچتا ہے جنہوں نے اپریل 2014ء میں حامد میر پر حملے کے بعد غلیل کی بجائے دلیل کے انتخاب کی تجویز دی تھی۔ تاریخ کے پیچ و خم سے گزرتے ہوئے اس سوال کی بازگشت بالآخر جنوری 1965ء تک پہنچتی ہے جب ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ ضمیر (قریشی) کیوں قتل ہوتا ہے؟
بشکریہ روزنامہ جنگ